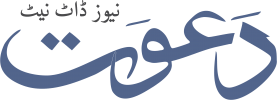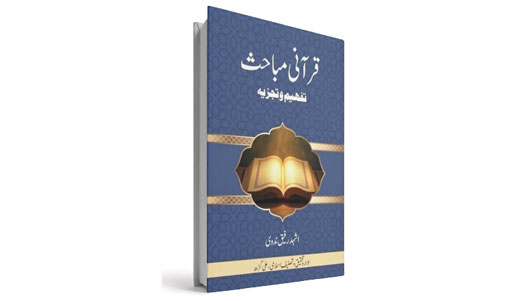
قرآنی مباحث، تفہیم وتجزیہ : اہم موضوعات پر مقالات کا مجموعہ
ابو سعد اعظمی
مولانا اشہد جمال ندوی مدرسۃ الاصلاح کے خوشہ چیں، ندوہ کے فیض یافتہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی آغوشِ تربیت کے پروردہ ہیں۔ جماعت اسلامی کی طلبہ ونگ ایس آئی او سے ان کا تعلق رہا، پھر جماعت اسلامی ہند کے قافلہ میں شامل ہوئے اور عہد وفا پر پوری استقامت کے ساتھ قائم ہیں۔ تقریر، دروس قرآن اور تربیتی پروگرام کے ساتھ ساتھ قلم و قرطاس سے بھی ان کا رشتہ رہا ہے۔ سید حامد سینئر سکنڈری ہائی اسکول، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں استاذ ہیں۔ادارہ تحقیق وتصنیف اسلامی، علی گڑھ کے سکریٹری اور اس میں قائم مسجد کے مستقل خطیب ہیں۔ تدریس اور انتظامی امور کی نگرانی کے پیش نظر قلم و قرطاس سے ان کا رشتہ کمزور ہوتا گیا۔ ایام شباب میں ادارہ علوم القرآن سے وابستگی اور اس کے مشن سے گہرے تعلق کی بنا پر قرآنیات پر ان کے جو مقالات شائع ہوئے وہ ان کی فکری پختگی اور قلمی مہارت کے آئینہ دارہ ہیں لیکن بعد میں وہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا۔ کاش کہ انہوں نے قلم کی اس امانت کو بھی انتظامی امور کے ساتھ کماحقہ سنبھالا ہوتا تو دنیائے قرآنیات ان کی گراں قدر نگارشات سے فیض یاب ہوتی۔
زیر تعارف کتاب مولانا اشہد رفیق ندوی کے ان قرآنی مقالات کا مجموعہ ہے جو گزشتہ تیس سال سے زائد کے دورانیے (جولائی-دسمبر ۱۹۸۷ء تاجنوری-جون ۲۰۲۱ء) میں مختلف اوقات میں تحریر کیے گئے تھے۔ اس میں چار مرکزی عناوین کتاب ہدایت، تدریس قرآن، اکابر کی خدمات: تعارف و تجزیہ اور اعتراضات کا جائزہ کے تحت مختلف مقالات شامل ہیں۔ تقدیم کے علاوہ ابتدائی ۱۲۵ صفحات میں علوم القرآن کے مختلف گوشوں سے بحث کی گئی ہے۔ سب سے پہلے قرآن وسنت کی روشنی میں قرآن کی امتیازی خصوصیات اور اس کی تاثیر کو واضح کرتے ہوئے قرآن کے اوصاف و مطالبات کو بیان کیا گیا ہے۔ تاثیر قرآن کے ضمن میں حضرت عمر فاروقؓ کا واقعہ قبول اسلام، عتبہ بن ربیعہ کا تلاوت قرآن سن کر متاثر ہونا، شاہ حبشہ نجاشی کا قرآنی آیات کو سن کر زار وقطار رو پڑنا، لبید کا ہمیشہ کے لیے شاعری کو تج کر دینا جیسے تاریخ کے مشہور اور اہم واقعات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے بعد مرحلہ درمرحلہ یعنی عہد نبوی، عہد صدیقی اور عہد عثمانی میں حفاظت قرآن کی ترتیب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس ضمن میں حفاظت قرآن کا الٰہی وعدہ اور اس کے ایفاء کی عملی تدابیر کا جائزہ لیتے ہوئے نزول قرآن میں تدریج کی حکمت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے اور مختلف عناوین مثلاً قلب نبوی کی تقویت، امتِ مسلمہ کی تربیت، نئے مسائل میں رہ نمائی اور کلام الٰہی ہونے کی دلیل جیسے عنوان قائم کرکے بتدریج نزول قرآن کی حکمت کو واضح کیا گیا ہے۔ وحی کی تعریف، نزول وحی کے طریقے، اس کی اقسام، قرآن اور وحی، کشف، الہام وغیرہ میں فرق کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں سورتوں کی ترتیب اور اجتہاد صحابہ کے عنوان سے شامل دو مقالات بحث و تحقیق اور مصنف کی علمی بصیرت اور جادہ پیمائی کا آئینہ دار ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مصنف نے اس میں بحث وتحقیق کا جو منہج اختیار کیا ہے اس کی افادیت آج بھی ہے۔ جبکہ دیگر مقالات کے مباحث علوم القرآن کی روایتی کتب میں بھی موجود ہیں اور گزشتہ چند سالوں میں علوم القرآن کے ان پہلووں پر اردو میں کافی مواد شائع ہو چکا ہے۔ مباحث فی علوم القرآن از مناع قطان وصبحی صالح کے اردو تراجم اور مناہل العرفان فی علوم القرآن از علامہ زرکشی نیز علوم القرآن (دو جلدیں) از مولانا گوہر رحمان وغیرہ میں اس طرح کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ مستشرقین کے اثرات کے زیر اثر جمع وترتیب قرآن کے حوالہ بعض نئے اعتراضات بھی سامنے آ رہے ہیں اور بعض مسلم اسکالرز جمع وترتیب، اعراب، نقطہ اور قرأت وغیرہ کے حوالے سے روایتی موقف سے ہٹ کر نئے زاویے پیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد عنایت اللہ سبحانی اور ڈاکٹر شہزاد سلیم کی کتابیں اس ضمن میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ جمع وتدوین آیات و سورتوں کے حوالہ سے یہ بحث بھی اب منقح ہو چکی ہے کہ آیات وسور کی ترتیب یا تعداد میں صحابہ کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا، بعض علماء کی طرف اگر اس سے ہٹ کر کوئی رائے منسوب کی جاتی ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے ان مباحث کی اشاعت سے قبل اگر اس پر نظر ثانی اور حذف واضافہ سے کام لیا گیا ہوتا تو اس کی افادیت دو چند ہوتی۔
تدریس قرآن کے تحت تین مقالات شامل ہیں۔ ان میں ہندوستان کے چند اہم مدارس دار العلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مدرسۃ الاصلاح، جامعۃ الفلاح، جامعہ اشرفیہ، جامعہ سلفیہ اور جامعہ دار السلام عمر آباد میں تدریس قرآن کا جائزہ، وہاں کے نصاب میں اصول تفسیر وعلوم القرآن کی صورتحال کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور مصنف نے ٹیبل کی مدد سے وہاں کی حقیقی صورتحال کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ مصنف کے اعداد وشمار اور صورتحال بیس سال قبل کے ہیں۔ اس طویل دورانیہ میں یقیناً وہاں کی صورتحال میں کچھ مثبت تبدیلیاں رونما ہوئی ہوں گی، مقالہ اس بات کے ذکر سے خالی ہے کہ کیا ان مدارس میں گزشتہ دو دہائی میں کوئی مثبت تبدیلی رونما ہوسکی یا ابھی اسی روایتی منہج پر اڑے ہوئے ہیں۔ مصنف کے اس اندیشہ سے شاید ہی کسی کو اختلاف ہو کہ ’’اگر یہ مدارس انیسویں اور بیسویں صدی میں مروج نظام و نصاب کو ہی حرزِ جاں بنائے رہے تو اس بات کا بڑا اندیشہ ہے کہ اس نظام ونصاب کے زیرِ سایہ پروان چڑھنے والے طلبہ اور علما اکیسویں صدی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کامیاب نہ ہوسکیں گے‘‘۔ (ص۱۴۳) ایک مقالہ میں اقرأ فاؤنڈیشن کے تیار کردہ نصاب کا تعارف کرایا گیا ہے۔
اکابر کی خدمات : تعارف وتجزیہ کے تحت مکی بن ابی طالب اور سفیان بن عیینہ کی تفسیری خدمات کا ذکر ہے۔ اصول تفسیر میں مولانا فراہی کی انفرادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مولانا ندوی کا یہ اقتباس فضلاء مدرسۃ الاصلاح کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتاہے کہ ’’فن اصول تفسیر میں مولانا فراہیؒ نے جو کچھ لکھا ہے ان میں کچھ مباحث مکمل تو کچھ ہنوز تشنۂ تکمیل ہیں۔ مولانا نے جن کمزوریوں کی نشان دہی کی ہے اور غور وفکر کے جو نئے دروازے وا کیے ہیں، اس نہج پر کام آگے بڑھانے کی ضرورت ہے‘‘۔ (ص۱۸۴) کاش مولانا نے خود ہی اس سمت میں قدم بڑھایا ہوتا اور تشنۂ تکمیل پہلوؤں کے اتمام کے لیے اپنے کو وقف کیا ہوتا تو یقیناً یہ قرآن کی ایک اہم خدمت ہوتی اور فکر فراہی کے متوسلین کے لیے گراں قدر تحفہ بھی۔
ایک مقالہ میں ابن تیمیہ اور فراہی کے مناہج تفسیر کا تقابلی مطالعہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔فاضل مصنف نے وضاحت کی ہے کہ ’’شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کے بارے میں زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ وہ تفسیر بالرائے کو مطلق حرام قرار دیتے ہیں۔۔۔ لیکن ابن تیمیہ کے بارے میں یہ رائے صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ ابن تیمیہؒ نے افراط وتفریط کے درمیان ایک معتدل راہ پیدا کی ہے۔ وہ ایسی تفسیر کو ضرور حرام کہتے ہیں جو محض ظن وتخمین کی بنیاد پر کی گئی ہو لیکن اگر کوئی شخص قرآن وسنت، روایات وآثار، لغت واسالیب، اسبابِ نزول، ناسخ ومنسوخ اور تمام ضروری معلومات کی روشنی میں تفسیر کرتا ہے تو وہ اسے عین واجب و مطلوب قرار دیتے ہیں‘‘۔ (ص۱۹۶-۱۹۷)۔اس کے بعد مولانا امین احسن اصلاحیؒ کی مبادی تدبر قرآن کے حوالہ سے فن اصول تفسیر پر روشنی ڈالی گئی ہے نیزادارہ علوم القرآن کے حوالہ سے محمد یٰسین مظہر صدیقیؒ کی قرآنی نگارشات سے بحث کی گئی ہے۔ آخر میں اصلاحی مصنفین کے اردو تراجم قرآن اور مدرسۃ الاصلاح کی قرآنی خدمات بھی زیر بحث آئی ہیں۔ فاضل مصنف کا یہ اقتباس مدرسۃ الاصلاح سے ان کے قلبی تعلق غماز ہے ’’۔۔۔مدرسۃ الاصلاح کا یہ دعویٰ بالکل درست ہے کہ اس کا ہر فارغ بحر قرآن کا شناور ہے، جو کچھ لکھا قرآن سے لکھا، قرآن کے بارے میں لکھا اور خدمت قرآن کی غرض سے لکھا ہے۔ تصنیف وتالیف کا موضوع جو بھی ہو اس کا جوہر اور خوشبو قرآن سے کشید ہوگا‘‘۔ اللہ تعالیٰ مولانا ندوی کے اس حسن ظن کو باقی رکھے اور فضلاء مدرسۃ الاصلاح کے دلوں میں خدمت قرآن کے جذبہ کو موجزن کردے۔
کتاب کا آخری جزو اعتراضات کے جائزہ کے عنوان سے ہے۔ جس میں علامہ شبلی کی سیرت النبی کے حوالہ سے مشرکین مکہ کی قرآن سے مخاصمت کے اسباب ومحرکات کا تجزیہ کرتے ہوئے عصر حاضر میں اس کی معنویت کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی سیاق میں رسول اکرم ﷺ پر قریش کے مظالم کا جائزہ لیتے ہوئے عہد مکی کی عصری معنویت پر بھی اظہار خیال کیا گیا ہے۔اعتراضات کے جائزہ کے عنوان سے شامل تین مقالات میں سے دو کے سلسلہ میں یہ وضاحت نہیں آسکی ہے کہ ان کی اشاعت کہاں روبعمل آئی ہے۔
کتاب میں بحث و تحقیق کے جدید اصولوں کی رعایت کی گئی ہے۔ اس کے مطالعہ سے قرآن مجید کے کتاب ہدایت ہونے کا پہلو، نیز اس کی امتیازی خصوصیات و اوصاف کا علم ہوتا ہے۔ وحی کے طریقے، اس کی اقسام اور جمع وتدوین قرآن کی بحث نیز آیات و سورتوں کی ترتیب سے متعلق اہم معلومات سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح اکابر علماء مکی بن ابی طالب، سفیان بن عیینہ، ابن تیمیہ، فراہی، اصلاحی اور یٰسین مظہر صدیقی نیز اصلاحی فضلاء کی قرآنی خدمات اور ان کے منہج کا پتہ چلتا ہے۔ کتاب کی طباعت عمدہ ہے اور پروف کی بہت معمولی غلطیاں راہ پاگئی ہیں۔
***
ہفت روزہ دعوت – شمارہ 24 اگست تا 30 اگست 2025